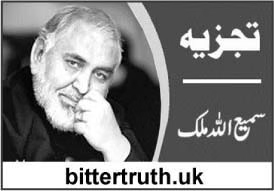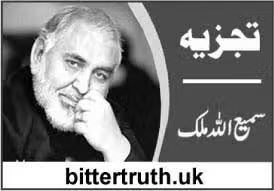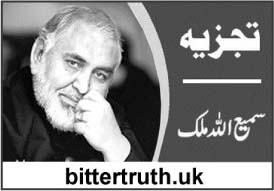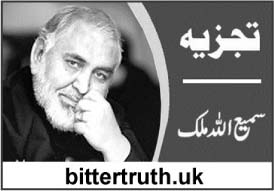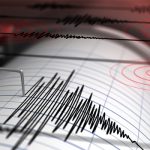مساجدو مدارس کے ملازمین کو تنخواہیں اور دیگر مراعات ان کے معاشرتی مقام سے بہت کم ملتی ہیں اور ان کی بنیادی ضروریات کےحوالے سے یہ بہت ہی کم ہیں۔ یہ ایک معروضی حقیقت ہے جس کا چند بڑے اور معیاری اداروں کو چھوڑ کر، جن کا تناسب مجموعی طور پر شاید پانچ فیصد بھی نہ ہو، ملک میں ہر جگہ مشاہدہ کیا جا سکتا ہےبلکہ بہت سے حلقوں کے نزدیک اس قسم کے لوگوں کا معاشرے میں موجود نہ رہنا ہی ان کے لیے عافیت کا باعث ہے۔ اس لیے مساجد و مدارس کے نظام سے تعلق رکھنےوالے ملازمین کی معاشی ضروریات،معاشرتی اسٹیٹس اورحقوق عام طور پربہت کم زیربحث آتےہیں ،یہ دراصل ایک بڑے اجتماعی مسئلہ بلکہ المیہ کا ایک جزوی پہلو ہے جس کا تعلق ہمارے مجموعی معاشی نظام اور معاشرتی رویوں سے ہے۔ ہمارے موجودہ معاشی نظام کی بنیاد جاگیردارانہ اور سرمایہ دارانہ نظام اور سوچ پر ہے، اس لیے یہ معاشی اور معاشرتی دونوں حوالوں سے طبقاتی ہے۔ اونچ نیچ کی نفسیات کے حوالے سے ہے اور بعض طبقوں کی ہر حال میں بالاتری اور بالادستی کی اساس پر ہے جس کے افسوسناک مظاہر ہمیں قدم قدم پر دکھائی دیتے ہیں مگر ہم خاموشی کے ساتھ آنکھیں بند کر کے وہاں سے گزر جاتے ہیں۔ میں پنجاب میں پیدا ہوا ہوں اور پنجاب میں ہی رہتا ہوں، مگر میرا اصل تعلق مانسہرہ (ہزارہ) کی سواتی برادری سے ہے۔ گزشتہ ماہ میں مانسہرہ گیا تو مجھے بتایا گیا کہ وہاں محکمہ مال کے کاغذات میں امام مسجد اور مولوی کو ’’کمین‘‘ کے خانے میں لکھا جاتا ہے اور وہ اسی اسٹیٹس کا حامل سمجھا جاتا ہے۔ خدا جانے پنجاب اور اور سندھ کی کیا صورتحال ہے لیکن ہزارہ کے بارے میں مجھے یہی بتایا گیا ہے۔ یہاں دو سوال سامنے آتے ہیں۔ایک یہ کہ کیا مالک اور کمین کی یہ اصطلاح اور معاشرتی درجہ بندی شرعی احکام کے حوالے سے درست ہے؟اور دوسرا سوال یہ کہ خدا نخواستہ اس تقسیم کو کسی درجے میں تسلیم بھی کر لیا جائے تو کیا مولوی، امام اور دینی خدمات سرانجام دینے والے لوگ اسی حیثیت کے حامل ہیں کہ انہیں ’’کمین‘‘ کے کھاتے میں شمار کیا جائے؟
میرے نزدیک یہ دونوں سوال سنجیدگی کے ساتھ غور و خوض کے متقاضی ہیں۔ اس صورتحال کی اصلاح کے لیے معاشی نظام اور معاشرتی رویے دونوں میں انقلابی تبدیلی کی ضرورت ہے۔ اگر ایک اسلامی ریاست کی تشکیل اور اسلامی معاشرہ کے قیام میں ہمارے لیے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور خلافتِ راشدہ کے فیصلے معیار اور راہنما ہیں تو ہمیں جاگیردارانہ نظام اور جاگیردارانہ کلچر دونوں سے نجات حاصل کرنا ہوگی اور سرمایہ دارانہ نفسیات اور سوچ سے پیچھا چھڑانا ہوگا جس کے لیے طبقاتی نظام کا خاتمہ سب سے زیادہ ضروری ہے۔یہ بات بھی ہمارے پیش نظر رہنی چاہیے کہ معاشرتی انقلاب اور تبدیلیاں محض قانون سے نہیں ہوا کرتیں۔ قانون بھی ایک درجے میں ضروری ہے، لیکن اصل تبدیلی اور اصلاح ایمان و عقیدہ اور اخلاق و عادات کے ذریعے ہوتی ہے اور اس کے لیے مسلسل فکری اور سماجی جدوجہد درکار ہے۔ ہمارا ایک المیہ یہ بھی ہے کہ ہم نے ہر سماجی تبدیلی اور معاشرتی اصلاح کے لیے سیاسی نعرے بازی کو ضروری قرار دے لیا ہے اور صرف قانون کے نفاذ کو کافی سمجھ رکھا ہے جس کی وجہ سے کسی صحیح مقصد کے لیے بھی ہماری جدوجہد ایک حد سے آگے بڑھ کر ناکامی کا شکار ہو جاتی ہے۔ جمعیۃ علماء اسلام نے ۱۹۷۰ء کے عام انتخابات کے موقع پر مولانا محمد عبد اللہ درخواستی، مولانا مفتی محمود، مولانا غلام غوث ہزاروی، مولانا پیر محسن الدین احمد (مشرقی پاکستان) اور مولانا عبید اللہ انور رحمہم اللہ کی قیادت میں اپنے انتخابی منشور میں اس مسئلے کے حل کی طرف پیشرفت کے لیےسرکاری زمینیں بے زمین کاشتکاروں میں تقسیم کرنے،انگریزی استعمار کے دور میں دی گئی جاگیریں ضبط کرنے،اور سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں ہوشربا تفاوت کو ختم کر کے پہلے ایک اور دس کے تناسب پر لانے، اور پھر بتدریج ایک اور پانچ کے تناسب پر فکس کر دینے کا وعدہ کر کےمسئلے کے حل کے آغاز کی ایک صورت پیش کی تھی۔ جمعیۃ علماء اسلام کی موجودہ قیادت کو اپنے مرحوم بزرگوں کا یہ موقف اور ۱۹۷۰ء کا یہ انتخابی منشور خواب میں بھی شاید یاد نہ آتا ہو، مگر جاگیردارانہ اور سرمایہ دارانہ نظام، کلچر اور نفسیات کے خاتمے کا آغاز اسی قسم کی کارروائیوں سے ہوگا اور کسی انقلابی عمل کے بغیر محض نعروں سے کچھ نہیں ہوگا۔مسجد و مدرسہ کا نظام بھی اسی معاشرے اور کلچر کا حصہ ہے اور عام طور پر دینی تعلیم و تربیت کے باوجود اسے اس کلچر اور مجموعی نفسیات سے الگ کر کے نہیں دیکھا جا سکتا۔ ظاہر بات ہے کہ جب مولوی اور امام مسجد کمّیوں اور لاگیوں میں شمار ہوگا تو اس کے ساتھ معاملہ بھی اسی جیسا ہوگا، خصوصا جب اس کمّی اور لاگی کو معاشرے کے لیے غیر ضروری، بلکہ معاشرے پر بوجھ سمجھا جائے گا تو وہی کچھ ہوگا جو ہو رہا ہے۔ اس لیے اصل ضرورت تو اس نظام اور کلچر کو بدلنے کی ہے اور اس کے لیے عوامی سطح پر منظم اور مربوط تحریک اور جدوجہد ناگزیر ہے لیکن اس سے ہٹ کر اس مسئلے سے نمٹنے اور اس کی تلخی کو کم کرنے کے لیے دینی جماعتوں، بڑے مدارس کے منتظمین اور خاص طور پر دینی مدارس کے وفاقوں کو اس پر غور کرنا چاہیے اور میں طالب علمانہ حیثیت سے اس سلسلے میں دو اصولوں کی طرف مساجد و مدارس کے منتظمین اور ان کو چلانے والی کمیٹیوں کو توجہ دلانا ضروری سمجھتا ہوں۔ ’’شاید کہ اتر جائے ’کسی‘ دل میں مری بات‘‘۔ ایک یہ کہ جب کوئی شخص خود کو کسی اجتماعی دینی کام کے لیے وقف کر دے اور کسی ادارے سے اس طور پر وابستہ ہو جائے کہ وہ اپنی ضروریات کے لیے اور کوئی کام نہ کر سکتا ہو تو اس کی اور اس کے زیر کفالت افراد کی معاشی کفالت شرعاً اس ادارے کے ذمے ہوتی ہے۔ اور کفالت کا معیار اس ادارے کے افراد اپنی مرضی سے نہیں طے کریں گے، بلکہ انہیں دوسرے عام شہریوں کے معیارِ زندگی کو ’’لا وکس فیہا ولا شطط‘‘ کے درجے میں بنیاد بنانا ہوگا۔دوسری بات یہ کہ صاحبِ ہدایہ نے حضرت امام ابوحنیفہؒ کا بیان کردہ یہ اصول ذکر کیا ہے کہ ’’لا رضاء مع الاضطرار‘‘ یعنی مجبوری کی رضا کا اعتبار نہیں ہے۔ اس کا مطلب مذکورہ مسئلہ کے حوالے سے میری سمجھ میں یہی آتا ہے کہ کوئی شخص اگر اضطرار یا مجبوری کی وجہ سے اپنے معروف حق سے کم پر راضی ہو گیا ہے تو اس کی اس رضا کا اعتبار نہیں ہے اور شرعاً وہ اسی حق کا حقدار ہے جو معروف حق کے طور پر اسے حاصل ہونا چاہیے۔میرا خیال ہے کہ اگر چند بڑے دارالافتاء اور وفاق المدارس العربیہ اس سلسلے میں تمام پہلوؤں کا جائزہ لے کر ملک بھر کی مساجد و مدارس کے لیے کوئی اجتماعی ضابطۂ اخلاق طے کر دیں تو دینی خدمات سرانجام دینے والے معاشرے کے اس مظلوم ترین طبقے کی دادرسی کی کوئی صورت نکل سکتی ہے۔